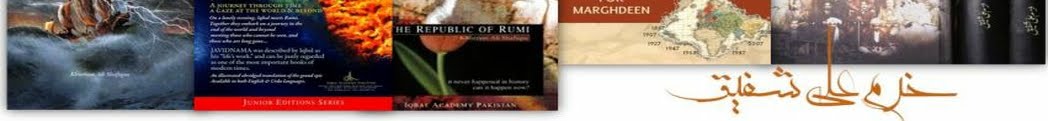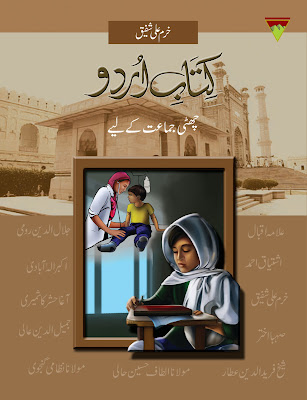نام ہی کافی ہے؟ جی نہیں۔
"اُردو ادب کی اسلامی
تحریک" کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں کچھ تصوّرات ابھرتے ہوں گے کیونکہ ادب
کے بارے میں آپ کے ذہن میں بعض مفروضے موجود ہیں اور بحمدللہ آپ اسلام کے بارے
میں بھی کچھ خیالات پہلے سے رکھتے ہیں۔ گزارش ہے کہ وہ ساری باتیں ایک طرف رکھ کر
یہ سمجھ لیجیے کہ "اُردو ادب کی اسلامی تحریک" ایک خاص اصطلاح ہے۔ یہ
میں نے اپنی طرف سے نہیں بنائی ہے۔
میں اس اصطلاح میں صرف اس قدر تبدیلی کی تجویز پیش کرتا ہوں
کہ اسے اُردو تک محدود نہ کیا جائے کیونکہ اس کا اظہار فارسی، انگریزی اور بعض علاقائی زبانوں میں بھی ہوا۔ بہرحال چونکہ
یہ تحریک اُردو سے شروع ہو کر دوسری زبانوں میں پھیلی اور علامہ کے حلقہء ادب نے
۱۹۳۵ء میں اسے "اردو ادب کی اسلامی تحریک" کہا تھا، اس لیے فی الحال میں
بھی اس کے لیے تاریخی حوالے کے طور پر یہی اصطلاح استعمال کرتا ہوں تاکہ یہ بات
بالکل واضح رہے کہ میں اُس خاص تحریک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جس کا حوالہ اور
تفصیلات میں نے اپنی انگریزی تصنیف "حیاتِ اقبال اور ہمارا عہد" میں
بیان کی ہیں۔
وہاں بیان کیے ہوئے اصولوں ہی کی بنیاد پر میں علامہ کے بعد
کے زمانے کے بعض مصنفین کو اِس تحریک سےمنسوب کرتا ہوں۔ سب سے اہم خصوصیت
جو بیان کی گئی تھی وہ یہ کہ اس تحریک نے اسلام کو ایک عالمگیر تحریک سمجھتے ہوئے
اُس کی تاریخ اور تہذیب کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھا ہے۔
اس لیے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اس تحریک کے دامن میں
ہمیشہ غیرمسلموں کے لیے بھی بہت کچھ تھا۔ مولانا حالی، اکبر الٰہ آبادی اور علامہ
اقبال کی شاعری سے ہندو بھی لطف اٹھاتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ علامہ کی اُردو شاعری
میں ہمیں رام چندرجی، گوتم بدھ، گرو نانک اور قدیم ہندو شاعر بھرتری ہری کی تعریف
میں نظمیں بھی ملتی ہیں۔
ان نظموں کے بارے میں انتہاپسند ہندووں کی طرف سے ایک غلط
فہمی ۱۹۲۴ء میں بانگِ درا کی اشاعت کے بعد پھیلائی گئی۔ وہ یہ تھی کہ ایسی نظمیں
علامہ نے صرف ابتدائی دور میں لکھیں اور بعد میں جب وہ مسلم قومیت کے علمبردار بن
گئے تو یہ انداز ترک کر دیا۔یہ بات جو حقیقت کے خلاف ہے، اتنی مشہور ہوئی کہ آج تک
دہرائی جا رہی ہے۔
سچ یہ ہے کہ میں نے یہاں علامہ کی جن نظموں کے حوالے دیے
ہیں یہ "مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا" کے بعد کی ہیں۔ علامہ کی
فارسی تصنیف جاویدنامہ خطبہء الٰہ آباد میں مسلم ریاست کی تجویز پیش کرنے کے دو
برس بعد ۱۹۳۲ء میں شائع ہوئی۔ اُس کے آسمانی سفر میں علامہ کے مرشد مولانا روم سب
سے پہلے اُنہیں ہندومت کی مقدس ہستی وِشوامتر کی خدمت میں لے جاتے ہیں۔ اسی کتاب
میں گوتم بدھ اور زرتشت کو پیغمبروں میں شمار کیا گیا ہے۔ سنسکرت کے قدیم شاعر
بھرتری ہری کو جنت الفردوس میں حوضِ کوثر کے قریب اشعار سناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
جنت الفردوس ہی میں دو بزرگوں کی گفتگو میں پنڈت موتی لال نہرو اور اُن کے بیٹے
جواہر لال نہرو کی تعریف کروائی گئی ہے حالانکہ سیاست میں علامہ اُس وقت بھی نہرو کے خلاف ڈٹے ہوئے تھے۔
حفیظ جالندھری بعض بزرگوں کی نظر میں بہت بڑے شاعر نہیں ہیں
لیکن مجھے اختلاف ہے جس کی تفصیل میں کسی علیحدہ پوسٹ میں پیش کروں گا۔ اس سے قطعِ نظر کہ وہ بڑے شاعر ہیں یا نہیں، یہ بات ہمیں
ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ انہوں نے صرف شاہنامہء اسلام اور پاکستان کا قومی ترانہ
ہی نہیں لکھے بلکہ کرشن کی شان میں دو نظمیں بھی لکھی تھیں۔ ایک شاہنامہء اسلام کی
پہلی جلد سے پہلے اور دوسری بعد میں۔ انہیں ہمیشہ اس پر فخر رہا کہ ان میں سے ایک
نظم کچھ عرصہ بنارس کے مندروں میں بھجن کے طور پر گائی گئی۔ "کچھ عرصہ"کی
تفصیل یہ ہے کہ جب پنڈتوں کو معلوم ہوا کہ
یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی ہے تو پابندی لگا دی۔
میں نے عرض کیا ہے کہ قیامِ پاکستان کے بعد اِس تحریک کے
پہلے بڑے مجتہد ابن صفی تھے۔ انہوں نے اس تحریک کا نام تو نہیں لیا لیکن اپنے
ناولوں کے "پیشرسوں" میں اور اپنے ایک طویل انٹرویو میں انہوں نے اپنے
فن کے جو مقاصد خود بیان کیے ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو پہلے سے اس تحریک کے بارے
میں بیان کیے جا چکے تھے۔ ویسے بھی اُردو میں جاسوسی کہانی کو فروغ دینے کی کوشش تو
خود علامہ اقبال نے ہی شروع کروائی تھی۔ اُن کے شاگرد حکیم احمد شجاع نے
"ہوشیار سراغرساں" کے عنوان سے جاسوسی ڈرامہ تحریر کیا تھا۔ اس سے پہلے
کی جاسوسی کہانیاں عموماً ترجمہ کی گئی تھیں، اس طرح یہ ڈرامہ اُردو میں شاید پہلی
طبعزاد جاسوسی کہانی ہو اگرچہ یہ معاملہ تحقیق طلب ہے۔
ابن صفی کے پہلے جاسوسی ناول کی ابتدا سبیتا دیوی کے فرضی
کردار سے ہوتی ہے۔ وہ ایک ہندو بیوہ ہے جس نے اپنی مسلمان سہیلی کی وفات کے بعد
اُس کے یتیم بچے کی ماں بن کر پرورش کی لیکن اُسے اُس کے مذہب پر قائم رکھا۔ کہانی
کی علامتی حیثیت پر غور کیجیے تو پاکستان بننے کے بعد بھارت کی مسلم قوم ایک طرح
سے یتیم بچے کی مانند تھی جس کی سرپرست وہاں کی ہندو اکثریت تھی۔ اس طرح مصنف کی
یہ خواہش معلوم ہوتی ہے کہ بھارت میں رہ جانے والے مسلمانوں سے ان کی مذہبی اور
قومی شناخت نہ چھینی جائے۔
پاکستانی ہدایتکار پرویز ملک کی فلم "دشمن" میں
ماں کا کردار سبیتا دیوی ہی سے ماخوذ معلوم ہوتا ہے۔ وہاں ایک عیسائی عورت ایک
یتیم مسلمان بچے کو گود لیتی ہے۔ وہ اُس کی تربیت اسلام کے مطابق کرتی ہے۔ بچہ جب
پوچھتا ہے کہ ہم ماں بیٹا ہونے کے باوجود علیحدہ طریقوں سے عبادت کیوں کرتے ہیں تو
وہ جواب دیتی ہے، "راستے الگ الگ ہیں، بیٹا ۔ لیکن منزل ایک ہے۔"
پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کی فلمی صنعت بھی اسی تحریک کی توسیع
ہے۔ حکیم احمد شجاع نے اُردو میں صرف جاسوسی کہانی ہی متعارف نہیں کروائی بلکہ وہ
پاکستانی فلمی صنعت کے بانیوں میں بھی شمار کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کی فلمی
کہانیاں اُن کے بیٹے انور کمال پاشا نے بطور ہدایتکار پیش کیں۔ ۱۹۵۰ء کی دہائی میں
پیش کی گئی ان فلموں میں مرکزی کردار عموماً ہندو ہیں۔ لیکن اُنہیں اُن کی علیحدہ
تہذیب اور مورتیوں کے ساتھ پیش نہیں کیا گیا، کسی "اقلیتی قوموں کے
میوزم" کا حصہ نہیں بنایا گیا بلکہ بغیر کسی جواز کے مرکزی کردار بنایا گیا
ہے۔ ہمیں ہندوستان میں شاید ہی کوئی مثال ملے کہ کسی بڑی فلم میں بغیر کسی جواز کے
مسلمان مرکزی کردار ہوں۔ وہاں مسلمان مرکزی کردار صرف "مسلم سوشل" فلم
میں ہوتے تھے جہاں انہیں مرکزی کردار دینے کا جواز پیش کرنے کے لیے قدیم مسلم
تہذیبی ماحول میں محدود کر دیا جاتا ہے۔
اب اُن قومی نغموں کی طرف آئیے جنہیں میں نے بیخودی کے نغمے
قرار دیا ہے۔ صرف یہی قومی نغمے متذکرہ تحریک کی پیداوار ہیں۔ ان میں سے جو قیامِ
پاکستان سے پہلے لکھے گئے اُن میں مسلم قومیت کا اظہار واضح طور پر کیا گیا ہے،
مثلاً "ملت کا پاسباں ہے" اور "پاکستان کا مطلب کیا؟"۔ لیکن
جو قیامِ پاکستان کے بعد لکھے گئے اُن میں عموماً ایسی اصطلاحات سے گریز کیا گیا
ہے جو صرف مسلمانوں سے مخصوص ہیں۔ اسلامی اقدار کو آفاقی تصوّرات کے ذریعے پیش کیا
گیا ہے۔اس طرح ایک مسلمان کے دل میں ان نغموں کو سنتے ہوئے مذہبی جذبہ ہی بیدار
ہوتا ہے لیکن پاکستان کے غیرمسلم شہری بھی انہیں سنتے ہوئے اجنبیت محسوس نہیں کر
سکتے۔ جیسے سوہنی دھرتی، جیوے پاکستان، میں بھی پاکستان ہوں، یہ وطن تمہارا ہے
وغیرہ۔
آپ قومی ترانے ہی کو دوبارہ سن لیجیے۔ تمام آفاقی اصطلاحیں
ہیں، جیسے "قوتِ اخوتِ عوام" وغیرہ ۔ پھر بھی بحیثیت مسلمان ہم یوں محسوس
کرتے ہیں جیسے یہ پاکستان کا نہیں بلکہ اسلام کا ترانہ ہے۔ آخری بند میں لفظ
"خدا" اس ترانے کا واحد لفظ ہے جسے مذہبی کہا جا سکتا ہے تو یہ قرآن
شریف کی اُس آیت کے مصداق ہے جس میں اہلِ کتاب کو دعوت دی گئی ہے کہ توحید کی
بنیاد پر مسلمانوں کے ساتھ متحد ہو جائیں۔ ویسے بھی صرف خدا کے لفظ کی وجہ سے اس
ترانے کی آفاقیت پر حرف نہیں آنا چاہیے کیونکہ جس وقت یہ ترانہ لکھا گیا ہے بالکل
اُسی زمانے میں امریکہ "اِن گاڈ وِی ٹرسٹ" کو سرکاری طور پر ماٹو بنا
رہا تھا یعنی "ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔"
یہ مثالیں تھیں اس بات کی کہ "اردو ادب کی اسلامی
تحریک" کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں
جو کچھ پیش کیا گیا وہ صرف مسلمانوں کے مطلب کی چیز تھا۔بالکل اُسی طرح جیسے
اسلامی فنِ تعمیر میں صرف مسجدیں ہی شمار نہیں کی جاتیں بلکہ الحمرا اور تاج بھی
آتے ہیں۔
اب اس اہم بات کی طرف بھی توجہ دیجیے کہ یہاں میں نے جو
مثالیں پیش کی ہیں یہ اُن چیزوں کی ہیں جنہیں اس تحریک نے صرف پیش ہی نہیں کیا
بلکہ انہیں عام مسلمانوں سے قبولِ عام بھی حاصل کروایا۔میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس
لیے بھی ممکن ہوا کہ ان مصنفوں نے مسلمانوں کا اعتماد حاصل کیا تھا۔ اس کے بارے
میں اس قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے ایسی چیزیں لکھ
رہے ہوں۔ اس لیے مسلمانوں نے یہی محسوس کیا جیسے ان تحریروں میں اکبر کا دینِ
الٰہی نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا حوصلہ ایک نیا جنم لے رہا ہے۔
مجھے تجسس ہے کہ کیا بیسویں صدی میں کسی
اور تحریک نے بھی دنیا کے تمام بڑے مذاہب کی نمایندگی کی ہے جس طرح اس تحریک میں
ہوئی، بالخصوص اگر جاویدنامہ کو سامنے
رکھا جائے اور باقی مثالیں جو میں اُردو زبان سے پیش کی ہیں اُنہیں اسی کا تسلسل
سمجھا جائے۔ اٹھارہویں اور اُنیسویں صدی میں تو جرمن ادب اور گوئٹے کی صورت میں اس
طرح کی مثالیں موجود ہیں لیکن بیسویں صدی میں شاید ہماری تحریک سے باہر کوئی مثال
موجود نہیں کہ کسی زبان کے سب سے بڑے شاعر نے اپنی سب سے اہم تصنیف میں تمام عالمی
مذاہب کی نمایندگی اس طرح کی ہو جسے اُن مذاہب کے ماننے والے بھی پسند کریں اور مصنف
کے اپنے ہم مذہبوں کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو۔
یہ بات اُردو کے لیے اہم ہو سکتی ہے کیونکہ اس طرح اُردو کے
دامن میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن کی ضرورت ہمارے علاوہ دوسروں کو بھی ہے اور
وہ ضرورت ہم پوری کر سکتے ہیں۔
اُردو کے قومی اور سرکاری زبان ہونے کے معاملے میں بھی یہ
بات اہم ہو سکتی ہے۔ پاکستان وہ ریاست ہے جو مسلم قومیت کی بنیاد پر وجود میں آئی
لیکن اس نے اپنے قیام کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا تھا کہ یہاں غیرمسلموں کو بالکل
برابر کی شہریت حاصل ہو گی۔ ایسی ریاست کی قومی یا سرکاری زبان کے لیے شاید بہتر
ہو کہ اُس کے دامن میں ایسا ادب پروان چڑھ رہا ہو جس میں دونوں پہلو موجود ہوں،
صرف کوئی ایک پہلو نہیں۔
دلچسپ بات ہے کہ انگریزی میں بھی ایسا ادب اتنے بڑے ناموں
نے ایسے قبولِ عام کے ساتھ پیش نہیں کیا ہے۔ جبکہ ہماری اکثر علاقائی زبانیں پہلے
ہی سے اِس طرف مائل ہیں کیونکہ وہاں جلیل القدر صوفیوں کی شاعری میں یہ خصوصیات
پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم اُردو سےاس تحریک کو نکال دیتے ہیں تو علاقائی زبانوں کے
ساتھ اُردو کا ایک بہت مضبوط تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنگال میں
بھی کسی نہ کسی حد تک یہ معاملہ ضرور پیش آیا تھا لیکن ہم نے آج تک توجہ نہیں دی ہے۔
اس کی تفصیل آیندہ قسط میں پیش کروں گا۔
اِس قسط میں صرف یہ بات واضح کرنی تھی کہ جس ادبی تحریک کو
علامہ اقبال کے زمانے میں "اُردو ادب کی اسلامی تحریک" کا نام دیا گیا تھااُس
کی امتیازی خصوصیت کیا تھی اور کیا نہیں تھی۔ اُمید ہے کہ یہ واضح ہو گیا ہو گا۔ نیز
یہ بھی کہ اگر ہم اُردو کو سرکاری زبان بنانا چاہتے تو اُس کے لیے اس تحریک کی بازیافت
ضروری ہے۔