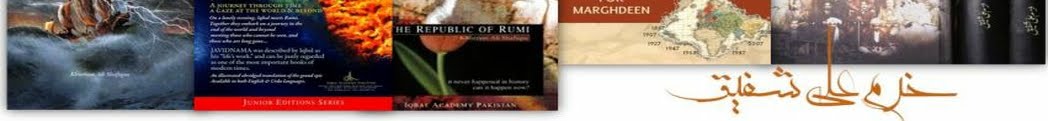ہفتہ، 28 نومبر، 2015
جمعہ، 27 نومبر، 2015
اقبال اور بھٹائی
شائع کردہ بذریعہ
Khurram Ali Shafique
شاہ عبداللطیف بھٹائی اور علامہ اقبال ایک ہی چراغ کی کرنیں ہیں۔ یہ وہ سچائی ہے جسے ہم ابھی تک نہیں پہچان پائے۔ شاید اس لیے کہ ہمارے
یہاں دونوں شاعروں کا مطالعہ غیرملکی ماہرین کے متعین کیے ہوئے اصولوں کی روشنی
میں ہوتا ہے۔
رومی، بھٹائی اور اقبال ہماری ثقافت کے تین مراحل کی
نمایندگی کرتے ہیں۔ مولانا روم نے اپنی زبان سے دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کی تفسیر
کر رہے ہیں مگر بعد میں آنے والوں نے اُن کی مثنوی کے بارے میں کہا کہ وہ فارسی میں قرآن ہے۔ رومی کے قریباً پانچ سو برس
بعد سندھ میں بھٹائی نے دعویٰ کیا کہ اُن کی شاعری میں قرآن کے معانی کے سوا کچھ
نہیں۔ یہ دعویٰ اُن کے مجموعہء کلام "شاہ جو رسالو" میں موجود ہے۔ اس
طرح بالواسطہ یعنی قرآن کے ذریعے اُن کا تعلق مولانا روم کے ساتھ بھی جڑتا ہے۔
علامہ اقبال غالباً بھٹائی سے واقف نہیں تھے۔ اس لیے کہ
۱۹۴۰ء سے پہلے بھٹائی کا نام سندھ سے باہر زیادہ معروف نہیں تھا اور یہ ہماری
بدقسمتی تھی۔ لیکن تعجب ہے کہ جو بات بھٹائی نے اپنے بارے میں کہی وہی علامہ نے قریباً دو سو برس بعد اپنے لیے دہرائی
کہ میرے اشعار میں قرآن کے معانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ دعویٰ اُن کی فارسی مثنوی
"اسرار و رموز" میں موجود ہے۔ اسی مثنوی کے آغاز میں انہوں نے یہ بھی
کہا کہ وہ مولانا روم کے حکم پر اُن کے پیغام کو نئے زمانے کے مطابق پیش کر رہے
ہیں۔
اس طرح اقبال اور بھٹائی کے درمیان پہلا تعلق یہ ہے کہ
دونوں نے قرآن کے معانی اپنی شاعری میں پیش کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس لحاظ سے دونوں
ہی مولانا روم کے شاگرد قرار پاتے ہیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی ادب میں بھٹائی کے ساتھ ایک نئے زمانے
کا آغاز ہوتا ہے جس میں اقبال بھی پیدا ہوئے اور ہم سب بھی جی رہے ہیں۔
بھٹائی سے پہلے کے صوفیانہ ادب میں صرف آفاقیت ہے۔ علاقائیت
کا احساس نہ ہونے کے برابر ہے۔ مولانا روم کی شاعری سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ
ترکی میں بیٹھ کر لکھی گئی۔ سعدی کی شاعری سے اندازہ نہیں ہوتا کہ ایران میں لکھی
گئی۔ امیر خسرو کی شاعری محسوس نہیں کرواتی کہ ہندوستان میں لکھی گئی، سوائے چند
"ہندی" گیتوں اور پہیلیوں کے جن کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا
سکتا کہ واقعی امیر خسرو کے ہیں۔ اسی لیے عرب کی لیلیٰ بڑی سہولت سے فارسی میں
منتقل ہونے کے بعد بالکل ایرانی لگنے لگتی ہے۔ بلہے شاہ نے پنجابی میں شاعری کی
لیکن سوائے اُن کی زبان کے اور کوئی بات ایسی نہیں جس سے معلوم ہو کہ یہ شاعر کہاں
رہتا ہے۔
جب ہم بھٹائی کی طرف آتے ہیں، ہمیں ایسی شاعری ملتی ہے جس
کی بنیادی اقدار تو وہی آفاقی ہیں اور پیغام بھی مولانا روم والا ہے لیکن یہ شاعری
اُسے گہرے علاقائی رنگ میں پیش کر رہی ہے۔ سوہنی، سسی، لیلاں، مومل اور ماروی
وغیرہ اس لحاط سے لیلیٰ اور شیریں سے مختلف ہیں کہ یہ اپنے اپنے علاقوں کی چلتی
پھرتی تصویریں ہیں اگرچہ ان کی روحیں پوری انسانیت کی نمایندگی کرتی ہیں۔
بھٹائی کے بعد شاعروں کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو وارث
شاہ، سچل سرمست، میاں بخش اور نجانے کتنے لوگوں سے ہوتا ہوا علامہ اقبال تک پہنچتا
ہےجہاں بڑی خوبصورتی سے یہ نکتہ بیان ہوتا ہے کہ ہم اپنے علاقے کی مٹی سے بنے ہوئے
پیالے میں عرب کی شراب پیش کر رہے ہیں :
بھٹائی اور اقبال کے درمیان دوسری قدرِ مشترک یہی ہے کہ
دونوں نے اپنے خطے کے رنگ میں اسلام کے آفاقی پیغام کو پیش کیا جو دراصل انسانیت
کا پیغام ہے اور صرف مسلمانوں تک بھی محدود نہیں۔ اس انداز کے خالق بھٹائی ہیں
جبکہ اسے تکمیل تک پہنچانے والے اقبال ہیں۔
اب تیسرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ بھٹائی کی شاعری جس خطے کی
نمایندہ ہے کیا وہ صرف سندھ ہے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ بھٹائی کی زبان اگرچہ
سندھی ہے لیکن وہاں اُس پورے خطے کی جھلکیاں ملتی ہیں جو آج پاکستان ہے۔ سوہنی
مہینوال اور سسی پنہوں ہی پر نظر ڈالیے تو کم سے کم سندھ، پنجاب اور بلوچستان ایک
وحدت میں بندھے ہوئے ضرور دکھائی دیتے ہیں۔ ذرا وسعت دیجیے تو خیبر پختونخوا اور
کشمیر کی جھلکیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔
ممکن ہے کہ بنگال بھی بھٹائی کے تخیل کی دنیا سے باہر نہ
رہا ہو۔ بھٹائی کا ایک شعر کچھ عرصے سے کافی مشہور ہو رہا ہے جس میں ملاح سے
کہا جا رہا ہے کہ فرنگی سے ہوشیار رہو۔ ممکن ہے کہ بھٹائی نے یہ بات اس لیے کہی ہو
کہ جنوبی سندھ میں یورپی تاجروں نے کوئی کارخانے بنائے تھے۔ لیکن جنگِ پلاسی کے
زمانے سے پہلے کہا ہوا یہ شعر بنگالی ملاح کے حسبِ حال بھی تو ہے۔
بھٹائی کے سب سے
اہم جانشین سچل سرمست نے سندھی کے علاوہ بھی پانچ چھ زبانوں میں شاعری کی۔ بعض
محققین کے دعوے کے مطابق ان میں اُردو بھی شامل ہے اگرچہ بعض دوسرے محقق اس میں
شبہ ظاہر کرتے ہیں۔ تب بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھٹائی سے اگلی ہی نسل میں ایک
سندھی شاعر موجودہ پاکستان کے اکثر علاقوں کی زبانوں میں شعر کہہ رہا تھا۔ اور سچل
ہی کے بارے میں بھٹائی کا قول مشہور ہے کہ میں نے جو دیگ چڑھائی ہے اُس کا ڈھکن یہ
شخص کھولے گا۔
اس طرح بھٹائی اور
اقبال کے درمیان تیسری قدرِ مشترک یہ ظاہر ہوتی ہے کہ دونوں کے شعری تخیل میں
پاکستان کا خاکہ موجود ہے۔ علامہ نے خود ہی کہا تھا کہ قومیں "شاعروں"
کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں۔
جو لوگ علامہ کی شاعری سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس
شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ "ڈرامائی مانولاگ" کی صورت میں لکھا گیا ہے۔
یہ وہ نظمیں ہیں جن میں کوئی کردار خودکلامی کرتا ہے۔ اُس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے
کہ وہ کہاں ہے، اُس کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے اور وہ کیا محسوس کر رہا ہے۔
مثلاً "ماں کا خواب"، "ایک حاجی مدینے کے راستے میں"،
"قیدخانے میں معتمد کی فریاد"۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ علامہ نے یہ
انداز مشہور انگریز شاعر رابرٹ براوننگ سے اخذ کیا۔ یہ انیسویں صدی کا شاعر تھا۔
اس انداز کا موجد اور امام سمجھا جاتا ہے۔
جس بات کی طرف شاید کبھی توجہ نہیں دی گئی وہ یہ ہے کہ
بھٹائی کے کلام کا اکثر حصہ بھی ڈرامائی مانولاگ ہی کی صورت ہیں ہے۔ انہوں نے پوری
پوری کہانیاں بیان نہیں کی ہیں۔ بلکہ وہ کسی لوک کہانی کے مشہور کردار کو لے کر
اُس کی زبانی کچھ کہلوانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ
ڈرامائی مانولاگ کا انداز براننگ سے سو برس پہلے ہی ہمارے یہاں بھٹائی بڑی کامیابی
سے برت چکے تھے۔ اتفاق سے یہی انداز بعد میں علامہ نے بھی اختیار کیا۔ یہ بھی بھٹائی
اور علامہ کے درمیان ایک گہری مماثلت ہے خواہ علامہ نے یہ انداز براوننگ ہی سے
کیوں نہ لیا ہو۔ اس طرح رومی، بھٹائی اور اقبال جیسی ایک اور مثلث بنتی ہے یعنی
بھٹائی، براوننگ اور اقبال۔ ان تینوں کے تقابلی مطالعے پر بھی کام ہونا چاہئیے۔
اس دفعہ وفاقی حکومت نے یومِ اقبال کی چھٹی منسوخ کر دی۔
دوسری طرف سندھ کی صوبائی حکومت نے بھٹائی کے عرس پر چھٹی کا اعلان کر دیا۔ بہت
ممکن ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ویسی ہی سازش ہو جیسی ۱۹۷۱ء سے پہلے کے زمانے میں
علامہ اقبال اور بنگالی شاعر نذرالاسلام کے درمیان کشمکش پیدا کر کے کی جاتی تھی۔
آج پھر پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ضرورت اس بات
کی ہے کہ ہم اپنی وحدت کی حفاظت کریں۔ علامہ
اقبال کے نام پر جشن ہو یا بھٹائی کے نام پر بہرحال ہم اُسے اُس وحدت کو پہچاننے
میں استعمال کریں گےجو تاریخی سچائی ہے۔
مزید مطالعے کے لیے بھٹائی کے بارے میں میرا انگریزی مضمون ملاحظہ کیجیے جو چند برس قبل ڈان اخبار میں شائع ہوا تھا۔
جمعرات، 26 نومبر، 2015
پاکستان کا مطلب کیا؟
شائع کردہ بذریعہ
Khurram Ali Shafique
"آنحضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تمام انسانیت میں اخوت، مساوات اور حریت کی بنیاد
رکھنا اوراُنہیں پروان چڑھانا تھا۔" یہ علامہ اقبال کی مثنوی کے دوسرے حصے
"رموزِ بیخودی" کے ایک باب کے عنوان کا ترجمہ ہے جو ۱۹۱۸ء میں شائع ہوئی۔
ان تینوں اصولوں یعنی اخوت، مساوات اور حریت کی وضاحت میں سے ہر ایک کی وضاحت کے
لیے ایک علیحدہ باب اس میں موجود ہے۔
اس کے قریباً بیس برس بعد جب علامہ نے انگریزی میں وہ لیکچر دئیے جو "ری کنسٹرکشن" یعنی "تشکیلِ جدید" کے عنوان سے بیحد مشہور ہوئے تو چھٹے لیکچر میں ریاست کے اسلامی تصوّر کی وضاحت کرتے ہوئے پھر کہا، "ایک عملی تصوّر کے طور پر توحید کی روح مساوات، اخوت اور حریت ہے۔" اخوت کے لیے انگریزی میں عام طور پر “fraternity” کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ لیکن علامہ نے اس کے لیے “solidarity” کا لفظ استعمال کیا۔ عام طور پر ہم اس کا ترجمہ یکجہتی کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں علامہ نے یہ لفظ اخوت ہی کے معانی میں استعمال کیا تھا۔ یہ بات ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ "رموزِ بیخودی" میں مکمل وضاحت موجود ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اخوت، مساوات اور حریت کی ترویج تھا۔
یہ مت سمجھیئے کہ یہ علامہ کا ذاتی خیال تھا اور عام مسلمان اس طرح نہیں سوچتے تھے۔ اگر آپ میری کتاب "اقبال: درمیانی دور"
پڑھیں تو خوشگوار حیرت سے دوچار ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ۱۹۱۴ء سے ۱۹۲۲ء کے
دوران صرف آٹھ برس کے عرصے میں پوری اسلامی دنیا پستی اور زوال کی انتہا سے نکل کر
دوبارہ عروج پر فائز ہو گئی اور وجہ یہی تھی کہ پورے عالمِ اسلام میں کسی نہ کسی وجہ سے توحید کا یہی مفہوم عام ہو رہا تھا۔
۱۹۱۴ء میں جب پہلی جنگِ عظیم شروع ہوئی تو مسلم
ریاستیں یورپ کی غلامی میں تھیں یا بدحال اور کمزور تھیں۔ ۱۹۱۸ء میں جنگِ عظیم کے
خاتمے پر یورپ بدحال اور کمزور ہو چکا تھا۔ اگلے چار برسوں میں پورے عالمِ اسلام
میں ایک نئی زندگی کی لہر دوڑ چکی تھی۔ ترکی نے یورپی حملہ آوروں کو نکال باہر
کیا۔ افغانستان نے برطانوی مداخلت مسترد کر کے کامل آزادی کا اعلان کر دیا۔ ایران
میں بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ ہندوستان
میں تحریک خلافت نے مسلمانوں کو زندہ قوم ہونے کا احساس دلا کر برطانوی استعمار سے
ٹکر لینے کا حوصلہ بخشا۔ شمالی افریقہ میں ریف کی خودمختار ریاست قائم ہوئی جس کے
بانی عبدالکریم نے مٹھی بھر سپاہیوں کی مدد سے ہزاروں اسپینی حملہ آوروں کو
شکست دے دی۔
ہم آج بھی "شکوہ" اور "جوابِ شکوہ" کا تذکرہ یوں کرتے ہیں جیسے اُن میں کھینچی ہوئی مایوسی اور زوال کی کیفیت ابھی تک ختم ہی نہیں ہوئی۔ حالانکہ وہ ۱۹۱۱ء اور ۱۹۱۲ء کی نظمیں ہیں۔ وہ کیفیت ۱۹۲۲ء میں ختم ہو گئی تھی جس کے بعد علامہ نے "خضرِ راہ" اور "طلوعِ اسلام" جیسی نظمیں لکھ کر بتایا کہ ہمارا سنہری زمانہ واپس آ چکا ہے:
اگلے تیس برس مسلمانوں کے سیاسی، علمی، تہذیبی، عروج کا زمانہ تھے۔ ۱۹۵۳ء
میں کیمبرج یونیورسٹی کے مشرقی علوم کے ماہر اے جے آربری نے "رموزِ
بیخودی" کا انگریزی میں ترجمہ کیا تو پیش لفظ میں رو رو کر دہائی دی کہ اسلامی دنیا میں تعلیم یافتہ مسلمانوں کی ایک پوری نسل تیار ہو چکی ہے جس کے
نزدیک توحید کے معانی اخوت، مساوات اور آزادی ہیں۔ اگر یہ رجحان ختم نہ کیا گیا تو
مغرب کی اخلاقی برتری ختم ہو جائے گی۔ پھر نہ سوئز کنال قبضے میں رہے گی نہ مشرقِ
وسطیٰ کا تیل۔ یورپ واپس "تاریک دور" میں چلا جائے گا۔ ایشیا پھر تہذیب
سکھانے پر مامور ہو جائے گا۔ خدا کے لیے مسلمانوں کو یقین دلاو کہ اخوت، مساوات
اور آزادی مغربی تصورات ہیں۔ ان کی علامت صرف فرانس کا جھنڈا ہے، پاکستان کے ساتھ
ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔
کیا ہم اِسے محض اتفاق سمجھیں کہ ٹھیک اُسی برس ہر مسلمان
ملک میں ایسی تحریکیں شروع ہو گئیں جنہوں نے جمہوریت کا راستہ روکا؟ اِسلام کے نام
پر تشدد، عدم رواداری اور روایت پرستی کے وہ تصورات پیش کیے گئے جو پچھلے تیس برس
کی جدوجہد میں کبھی نہیں سنے گئے تھے۔
اس کے ساتھ ہی پاکستان کا مطلب بدل گیا۔ تحریکِ پاکستان کے
زمانے میں نعرہ لگایا گیا تھا، "پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الٰہ الااللہ"۔
۱۹۵۴ء میں حکومت پر قابض ٹولے نے "منیر رپورٹ" شائع کر کے اس کی تردید
کی۔
 |
| تصویر بشکریہ عقیل عباس جعفری |
آج ہم پاکستان میں جو خرابیاں دیکھتے ہیں اُن کی وجہ بعض لوگوں
کے نزدیک یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا مطلب "لا الٰہ الا اللہ" سمجھ لیا
ہے۔ میرے خیال میں ہم نے پاکستان کا مطلب ٹھیک سمجھا ہے مگر "لا الٰہ
الاللہ" کا مطلب سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ اِس سلسلے میں اُسی شخص کی بات
بھلا ئے بیٹھے ہیں جس نے پاکستان کا تصوّر پیش کیا تھا۔ اگر ہم "اَیپل"
کمپیوٹر خرید کر اُس پر "وِنڈوز" پروگرام چلانے کی کوشش کریں جو "اَیپل"
کے لیے نہ ہوں تو کیسے چلیں گے؟ پاکستان ہم سے نہیں چلایا جا رہا تو حیرت کی بات
نہیں۔
مفکرِ پاکستان کے نزدیک لا الٰہ الااللہ کے عملی پہلو کی
روح اخوت، مساوات اور آزادی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم مغربی افکار قبول
کریں یا مغرب کی تقلید کریں۔ بلکہ جیسا کہ آربری صاحب نے گھبرا کر لکھا تھا، مطلب
اس کے برعکس دکھائی دے رہا تھا۔ یعنی اب ان اصولوں کے وارث ہم ہیں۔ کوئی اور نہیں۔
مغرب میں یہ تینوں الفاظ سب سے زیادہ فرانس کے جھنڈے کے ساتھ منسوب ہیں۔ وہی جھنڈا جسے پیرس پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد کروڑوں لوگوں نے جن میں مسلمان بھی شامل تھے، فیس بک پر دوپٹے کی طرح اپنے چہروں پر ڈال لیا تھا۔ لیکن خود فرانس نے کیا کیا؟ اُن معصوم بچوں کی لاشوں کی تصاویر بھی ہم نے دیکھیں جنہیں کسی نامعلوم دہشت گرد تنظیم نے نہیں بلکہ فرانس کی ذمہ دار حکومت نے موت کے گھاٹ اُتارا تھا۔ وہی حکومت جسے فرانسیسی شہریوں کی حمایت حاصل ہے۔ جو جمہوری حکومت ہے۔ کیا اس طرح اخوت، مساوات اور آزادی کی ترویج کی جاتی ہے؟
پاکستان حاصل کرتے ہوئے ہم نے کہا، "پاکستان کا مطلب
کیا؟ لا الٰہ الااللہ"۔ کیوں نہ پاکستان کی تعمیر کرنے کے لیے اُسی لا الٰہ
الااللہ کے عملی پہلو پر توجہ دی جائے۔ کیوں نہ کہا جائے کہ پاکستان کا مطلب اخوت،
مساوات اور آزادی ہے کیونکہ توحید کے عملی پہلو کی رُوح یہی اصول ہیں۔
منگل، 24 نومبر، 2015
جمیل الدین عالی اور قرآن
شائع کردہ بذریعہ
Khurram Ali Shafique
مولانا روم، شاہ عبداللطیف بھٹائی اور علامہ اقبال تین شاعر
ہیں جن کی شاعری کے بارے میں خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن شریف سے ماخوذ ہے۔
چند برس پہلے میں نے اس فہرست میں ایک اور نام کے اضافے کی تجویز پیش کی تھی: جمیل
الدین عالی۔ اس موضوع پر میرا مقالہ "جمہوری ادب" کے عنوان سے اقبال
اکادمی پاکستان کے تحقیقی مجلے اقبالیات میں شائع ہو چکا ہے۔
سب سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ قرآن شریف سے متاثر ہونے والا
ادب کبھی غیردلچسپ نہیں ہوتا۔ اس میں وعظ و نصیحت کی ایسی بھرمار بھی نہیں ہوتی جو طبیعت پر بوجھ ڈالے۔ کیونکہ
قرآن ہمیشہ "خیالات" سے زیادہ "عمل" پر زور دیتا ہے۔
مثنوی مولانا روم کے بارے میں کہا گیا کہ "فارسی میں قرآن" ہے۔ اسی مثنوی میں ایسی ایسی دلچسپ حکایات ہیں کہ آج تک لطیفوں کے طور پر سنائی جا رہی ہیں اور سنانے والوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ رُومی کی حکایت ہے۔
مثنوی مولانا روم کے بارے میں کہا گیا کہ "فارسی میں قرآن" ہے۔ اسی مثنوی میں ایسی ایسی دلچسپ حکایات ہیں کہ آج تک لطیفوں کے طور پر سنائی جا رہی ہیں اور سنانے والوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ رُومی کی حکایت ہے۔
بھٹائی نے اپنے بارے میں دعویٰ کیا کہ اُن کے مصرعوں میں
قرآن کے موتی چمک رہے ہیں۔ لیکن انہی مصرعوں نے عشق و محبت کی وہ داستانیں ہمیں
عطا کی ہیں جن کے نام اور حوالے ہمارے رومانی ادب کی جان ہیں، جیسے سوہنی مہینوال اور
سسی پنہوں وغیرہ۔
علامہ اقبال کی شاعری اپنے زمانے میں صرف خواص ہی نہیں بلکہ
عوام میں بھی مقبول تھی۔ اُن کے بارے میں اُردو میں پہلی باقاعدہ تصنیف جو ۱۹۲۶ء
میں شائع ہوئی اُس میں اُن کی مقبولیت کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اُن کی شاعری بہت
"رنگین" ہے۔ اس میں عشقیہ شاعری کے استعارے موجود ہیں۔ علامہ نے صرف
انہیں قوم کی محبت کی طرف موڑ دیا ہے۔ وہ زندہ تمنا "جو قلب کو گرما دے، جو
روح کو تڑپا دے" ہمیشہ عاشق کے دل میں ہوتی تھی۔ علامہ نے "دلِ عاشق"
کی بجائے "دلِ مسلم" کہہ کر نظم کی تاثیر بدل دی
مگر نظم کی رنگینی کم نہ ہونے دی۔
جمیل الدین عالی کے یہاں بھی ہمیں ایسے بہت سے شاہکار ملتے
ہیں جو بالکل انہی مثالوں کی طرح عوام میں مقبول ہوئے اور بالکل انہی شاعروں کے
کلام کی طرح وہاں بھی قرآنی تلمیحات اور قرآن شریف کے اثرات بڑے واضح ہیں۔
اس کی ایک مثال اسلامی سربراہی کانفرنس کے دوسرے اجلاس کے موقع پر لکھا گیا ترانہ "ہم مصطفوی ہیں"۔ یہ ترانہ بیحد مشہور ہے لیکن عام طور پر ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ صرف دوسری سربراہی کانفرنس سے منسوب تھا۔ یا صرف پی ٹی وی کی پیشکش تھا۔ ایسا نہیں ہے بلکہ تمام اسلامی ممالک سے موصول ہونے والے ترانوں میں سے اسے منتخب کر کے باقاعدہ قرارداد کے ذریعے کانفرنس کے مستقل ترانے کے طور پر منظور کیا گیا تھا۔ آج بھی جب کبھی کانفرنس کا اجلاس ہوتا ہے، کم سے کم اس کا سازینہ ضرور ترانے کے طور پر بجایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ اسلامی سربراہی کانفرنس کا سرکاری ترانہ ہے اس لیے ہم اسے عالمِ اسلام کا قومی ترانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اتنے غافل ہوں کہ ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ دورِ حاضر میں عالمِ اسلام کا ایک قومی ترانہ بھی ہے۔
اس کی ایک مثال اسلامی سربراہی کانفرنس کے دوسرے اجلاس کے موقع پر لکھا گیا ترانہ "ہم مصطفوی ہیں"۔ یہ ترانہ بیحد مشہور ہے لیکن عام طور پر ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ صرف دوسری سربراہی کانفرنس سے منسوب تھا۔ یا صرف پی ٹی وی کی پیشکش تھا۔ ایسا نہیں ہے بلکہ تمام اسلامی ممالک سے موصول ہونے والے ترانوں میں سے اسے منتخب کر کے باقاعدہ قرارداد کے ذریعے کانفرنس کے مستقل ترانے کے طور پر منظور کیا گیا تھا۔ آج بھی جب کبھی کانفرنس کا اجلاس ہوتا ہے، کم سے کم اس کا سازینہ ضرور ترانے کے طور پر بجایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ اسلامی سربراہی کانفرنس کا سرکاری ترانہ ہے اس لیے ہم اسے عالمِ اسلام کا قومی ترانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اتنے غافل ہوں کہ ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ دورِ حاضر میں عالمِ اسلام کا ایک قومی ترانہ بھی ہے۔
معنویت کے لحاظ سے یہ ترانہ اس قابل ہے کہ اس کی تشریح میں
پوری پوری کتابیں لکھی جائیں۔ میں صرف اس کے پہلے بند کے حوالے سے بعض اشارے پیش
کروں گا جن کا تعلق قرآن شریف سے ہے۔ اُس بند کے مصرعے ہیں:
سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وحدت فرقانی
روحِ اخوت، مظہرِ قوت، مرحمتِ
رحمانی
سب کی زباں پر سب کے دلوں میں اک
نعرہ قرآنی
اللہ اکبر، اللہ اکبر
سب سے پہلے یہ غور کیجیے کہ تینوں مصرعوں کے ہم قافیہ الفاظ
قرآن سے متعلق ہیں: فرقانی، رحمانی اور قرآنی۔ ہم جانتے ہیں کہ فرقان، قرآن شریف
کا لقب ہے اور رحمان اسے نازل کرنے والے
کا صفاتی نام ہے۔ اب اس بات کی داد دیجیے کہ یہ الفاظ جو قرآن کی طرف اشارہ کرتے
ہیں، ان میں سے ہر لفظ یہاں مسلمانوں کے اجتماع کی کوئی نہ کوئی صفت بیان کر رہا
ہے۔
اُن کی وحدت "فرقانی" ہے۔ یعنی ویسے تو وحدت کا
مطلب ہے فرق ختم ہو جانا مگر یہ وحدت حق و باطل کا فرق قائم بھی کر دیتی ہے اس لیے
"فرقانی" یعنی فرق قائم کرنے والی ہے۔ چونکہ یہ وحدت قرآن کی وجہ سے
پیدا ہوئی ہے جس کا لقب فرقان ہے، اس لیے بھی یہ فرقانی وحدت ہے۔
یہ وحدت ہماری اخوت کی روح کو بیان کرتی ہے مگر ہماری اخوت
کی روح کیا ہے؟ ہماری اخوت وقت کے ساتھ کوئی بھی روپ اختیار کر سکتی ہے مگر اُس کی
"روح" یعنی اُس کی اصل وہی واقعہ رہے گا جسے قرآن شریف میں بھی بیان کیا گیا
ہے کہ خدا کے احسان کو یاد کرو۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اُس نے تمہیں بھائی
بھائی بنا دیا۔ اس طرح یہ "روحِ اخوت" ہمیں رحمان کی طرف سے مرحمت ہوئی
ہے، وہی رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اُسی نے ہمیں روحِ اخوت بھی عطا فرمائی۔
اس لیے ہم سب کی زبانوں پر اور دلوں میں قرآن سے نکلا ہوا
ایک نعرہ ہے یعنی اللہ اکبر۔ یہ نعرہ صرف ہماری زبانوں پر نہیں بلکہ دلوںمیں ہے
کیونکہ دل کی گہرائیوں میں ہم اُس روحِ اخوت کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم خدا کی
بڑائی کے قائل ہو رہے ہیں۔ لیکن اُس کی بڑائی کا اعتراف ہم جن الفاظ میں کرتے ہیں
وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں بلکہ وہ قرآن ہی
کے الفاظ ہیں۔ البتہ وہ ہمارے دلوں سے نکل کر زبان پر آ رہے ہیں جیسے قران ہم پر
دوبارہ نازل ہو رہا ہو۔
ان تمام نکات کی خوبی یہ ہے کہ ان میں قرآن اور مسلمان کے
باہمی تعلق کے بارے میں ایسی بہت سی باتیں دہرائی گئی ہیں جن کی نشاندہی علامہ
اقبال نے کی تھی۔ مثلاً علامہ نے کہا تھا کہ مومن اگرچہ قاری نظر آتا ہے مگر حقیقت
میں قرآن ہے۔ اسی طرح یہاں قرآن سے متعلق الفاظ مسلمانوں پر منطبق ہو رہے ہیں۔
اِس کے علاوہ علامہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن اس طرح پڑھنا
چاہئیے جیسے یہ ہم پر دوبارہ نازل ہو رہا ہے۔ یہ دراصل علامہ کے والد کی نصیحت
تھی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اِس بند میں عملاً ہمیں ایک ایسے ہی تجربے سے روشناس
کروایا جا رہا ہے۔
میرا خیال ہے کہ وہ تمام شاعر جن کا تخلیقی وجدان قرآن شریف
سے متاثر ہوتا ہے، وہ صرف قرآن میں پیش کیے ہوئے احکامات ہی نہیں دہراتے بلکہ اُن
سے پہلے اِس سلسلے کے شاعروں نے جو کچھ
بیان کیا ہوتا ہے، وہ اُس کا احاطہ بھی کر لیتے ہیں۔
عالی خود بھی ماضی کے بعض شعرا کے ساتھ بالکل ایسے ہی ایک تعلق کا اعلان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ کہتے ہیں، "تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے اُس میں شامل ہے آواز میری۔" ایک اور جگہ کہتے ہیں، "شاہ لطیف سے برکت پائیں۔ علن اور عالی کی دعائیں۔" ایک جگہ پاکستان کو "اقبال کا اِلہام" قرار دیتے ہیں۔
عالی خود بھی ماضی کے بعض شعرا کے ساتھ بالکل ایسے ہی ایک تعلق کا اعلان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ کہتے ہیں، "تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے اُس میں شامل ہے آواز میری۔" ایک اور جگہ کہتے ہیں، "شاہ لطیف سے برکت پائیں۔ علن اور عالی کی دعائیں۔" ایک جگہ پاکستان کو "اقبال کا اِلہام" قرار دیتے ہیں۔
جمیل الدین عالی کی شاعری میں قرآنی اثرات کی یہ صرف ایک
مثال تھی جو "ہم مصطفوی ہیں" کے ایک بند کے حوالے سے پیش کی گئی۔ ایسی
بہت سی مثالیں ہیں اور صرف اُن کے مقبولِ عام قومی گیتوں ہی میں قرآن شریف کی اتنی
تلمیحات غیرمحسوس طریقے پر موجود ہیں جن پر مکمل کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ مثلاً "جیوے
پاکستان" کا مصرعہ شاید ہر شخص کو یاد ہو، "جھیل گئے دُکھ جھیلنے والے
اب ہے کام ہمارا۔" اِس مصرعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن شریف کی وہ آیت یاد
کیجیے جس میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، اُن کے
اچھے اعمال اُن کے ساتھ ہیں۔ تمہیں اُس کا صلہ دیا جائے گا جو تم کرو گے۔
مزید مطالعے کے لیے میرا مقالہ "جمہوری ادب"
ملاحظہ فرمائیے:
اتوار، 22 نومبر، 2015
آج وحید مراد کے بارے میں
شائع کردہ بذریعہ
Khurram Ali Shafique
چند ہفتے قبل میری کتاب Waheed Murad: His Life and Our Times شائع ہوئی ہے جو میرے خیال میں وحید مراد کی پہلی مکمل
سوانح حیات ہے۔ یہ کتاب آن لائن بک اسٹورز مثلاً امیزن وغیرہ سے با آسانی دستیاب
ہے۔ امید ہے کہ جلد ہی اس کا پاکستانی اڈیشن اور ترجمہ بھی پیش کر سکوں گا۔
البتہ ایک ویب سائٹ پہلے ہی حاضر کر چکا ہوں جہاں سے وحید
مراد کے بارے میں بہت سی مفید اور دلچسپ معلومات دستیاب ہو سکتی ہیں۔ اُس کا پتہ
یاد رکھنا بہت آسان ہے یعنی
جو لوگ اقبالیات کے موضوع پر میری تحقیق سے واقف ہیں وہ
شاید بخوبی واقف ہوں گے کہ میں نے وحید مراد کی سوانح کیوں لکھی ہے۔اس کی کافی
وضاحت پہلے ہی کر چکا ہوں ۔ اس لیے آج اُس موضوع سے ہٹ کر کچھ ایسی معلومات پیش کر
رہا ہوں جو شاید سب کی دلچسپی کا باعث ہوں۔ یہ دراصل میری وحید مراد کی سوانح کے
ابتدائی صفحات کا ترجمہ ہے اور وحید مراد کے خاندانی پس منظر پر مشتمل ہے۔
وحید مراد کے آبا و اجداد کسی زمانے میں دکن کی بہمنی سلطنت سے وابستہ تھے۔ یہ جنوبی ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک عظیم الشان حکومت تھی۔ وحید کے اجداد یہاں قریب قریب شاہی خاندان میں شمار ہوتے تھے۔ ۱۵۱۷ء میں یہ ریاست ابتری کی شکار ہو کر مختلف حصوں میں تقسیم ہونے لگی۔ اس موقع پر وحید کے اجداد نے کشمیر کے مسلمان حکمران کی دعوت پر وہاں ہجرت کی۔ اُس کے بعد کسی وقت اس خاندان کے لوگ "نَو بہمنی" یعنی نئے بہمنی کہلانے لگے۔
اس زمانے میں کشمیر دنیا بھر میں علم و ثقافت کے مرکز کے
طور پر مشہور ہو رہا تھا۔ اسے "ایرانِ صغیر" یعنی چھوٹا ایران بھی کہا
جاتا تھا۔ اٹھارہویں صدی کے اواخر میں یہاں کے حالات بھی بگڑنے لگے۔ کشمیر سے بہت
سے خاندان ہجرت کر کے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہونے لگے۔ نوبہمنی خاندان
بھی پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں منتقل ہو گیا۔ اس خاندان کے ایک شخص شیخ کرم الٰہی
تھے انیسویں صدی میں سیالکوٹ کی ایک بارسوخ شخصیت ہوئے جنہیں "رئیسِ
اعظم" بھی کہا جاتا تھا۔ ان کی حویلی کا نام "کرم لاج" تھا۔ اس کے
علاوہ بھی اس خاندان کے پاس بعض دوسری املاک تھیں، مثلاً "شیخاں دا باغ"
اور "بابے دی بیری" نامی کنواں وغیرہ۔
وحید کے دادا شیخ ظہور الٰہی مراد اِسی خاندان میں ۱۸۷۷ء
میں پیدا ہوئے۔ وہ اور اُن کے چھوٹے بہن
بھائی اس خاندان کے اولین افراد تھے جن کے ناموں کے آخر میں لفظ "مراد"
لگایا گیا۔ ان بہن بھائیوں کے نام ظہور الٰہی، فیروز الدین، خورشید بیگم، احمد بیہ
بی، مہر الٰہی اور فضل الٰہی تھے۔ وجہ معلوم نہیں ہے لیکن قیاس کے گھوڑے دوڑائے
جائیں تو سب سے پہلے تین باتیں سامنے آتی ہیں۔ مغربی ممالک کے برعکس ہمارے یہاں
نام کے آخری لفظ کے لیے کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں تھا اس لیے ہو سکتا ہے کہ ظہور
کی پیدایش سے اُن کے والدین کی کوئی "مراد" بر آئی ہو اس لیے یہ لفظ اُن
کے نام کے ساتھ لگا دیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ تصوف میں "مراد" ایک خاص
قسم کے مرید کو کہتے ہیں جسے پرودگار خود منتخب کر کے توحید کا مظہر بنا دے۔ ترکی
کے عثمانی سلطانوں میں بھی مراد بیحد مقبول نام تھا اور اِس نام کے کئی بادشاہ اس
خاندان میں گزرے تھے۔ مسلمان عام طور پر اُنہیں خلیفہ سمجھتے تھے اور ہندوستان میں
بھی اُن کے ساتھ عقیدت عام تھی۔
شیخ ظہور الٰہی مراد نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ کے اسکاچ مشن
اسکول میں حاصل کی۔ اُن کے اساتذہ میں مولوی میر حسن بھی شامل تھے جن کی سب سے
زیادہ شہرت علامہ اقبال کے اُستاد کی حیثیت میں ہے )علامہ نے اسی اسکول سے پرائمری
تعلیم اُس برس مکمل کی تھی جب ظہور پیدا ہوئے(۔ میر حسن ویسے بھی اپنے زمانے کی ایک ممتاز شخصیت تھے۔
وہ سر سید احمد خاں کے وفادار ترین ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ محمڈن ایجوکیشنل
کانفرنس کے بانیوں میں سے بھی تھے جو برصغیر میں مسلمانوں کی نمایندہ تنظیم تھی
اور بعد میں اسی تنظیم نے آل انڈیا مسلم لیگ کو جنم دیا۔
ظہور مولوی میر حسن
کے نمایاں شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اقبال اکادمی نے مولوی میر حسن کی جو سوانح
شائع کی ہے جسے صدارتی اقبال ایوارڈ بھی مل چکا ہے، اُس میں مولوی صاحب کے شاگردوں
میں ان کا نام اور مختصر تعارف شامل ہے۔ انہوں نے آگے چل کر قانون کی تعلیم حاصل
کی اور وکیل بن گئے۔ ان کے چھوٹے بھائی فیر الدین مراد نے طبعیات یعنی فزکس کی
تعلیم حاصل کی اور ایف ڈی مراد کے نام سے پورے برصغیر میں شہرت حاصل کی۔ وہ علیگڑھ
مسلم یونیورسٹی میں شعبہء طبیعات کے صدر بھی ہوئے۔ آج بھی علیگڑھ یونیوسٹی میں ایم
ایسی سی فزکس میں اول آنے پر اُن کے نام تمغہ "ایف ڈی مراد امام الدین
میڈل" دیا جاتا ہے۔ سائینس کے موضوع پر ایف ڈی مراد کی ایک تحریر اُس درسی
کتاب میں بھی شامل تھی جسے علامہ اقبال اور اُن کے شاگرد حکیم احمد شجاع نے
"اُردو کورس" کے عنوان سے مرتب کیا تھا۔
ظہور کے سب سے چھوٹے بھائی شیخ فضل الٰہی تھے۔ اُن کے
صاحبزادے انور مراد بعد میں پاکستان نیوی کے اعلیٰ عہدے دار ہوئے اور پھر ترکی اور
سری لنکا میں پاکستان کے سفیر بھی مقرر ہوئے۔
خود ظہور کسی زمانے میں بیگم صاحبہ بھوپال کے قانونی مشیر
بھی مقرر ہوئے۔ سیالکوٹ میں وہ غریب موکلوں کے مقدمے کسی معاضے کے بغیر لڑنے کے
لیے مشہور تھے۔ سماجی برائیوں کے خلاف احتجاجی تحریکوں میں بھی پیش پیش رہتے تھے
جن میں شراب نوشی اور حسن فروشی خلاف تحریکیں شامل تھیں کیونکہ یہ رجحانات
انگریزوں کی فوجی چھاونی کی وجہ سے پیدا ہونے تھے جس پر سیالکوٹ کے باشندوں کو سخت
اعتراضات تھے۔ ظہور چاہتے تھے کہ اُن کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور پھر وہ
تعلیم قوم کی خدمت میں صرف ہو۔ اُن کے سب سے بڑے لڑکے ظفر نے مرے کالج جموں سے
تعلیم حاصل کرنے کے بعد انجمن حمایت اسلام کے اسکولوں میں تعلیم دینے میں عمر صرف
کی اور ہیڈ ماسٹر کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ ظہور کی صاحبزادی انوری مراد نے بھی یہی
پیشہ اختیار کیا سیالکوٹ میں مشن گرلز اسکول کی وائس پرنسپل کے عہدے سے ریٹائر
ہوئیں۔
آخری زمانے میں ظہور کو ایک شدید ذاتی صدمے کا سامنا کرنا
پڑا۔ اُن کے سب سے چھوٹے لڑکے نذید احمد جن کے ابھی لڑکپن کے دن تھے، ٹی بی کے
شکار ہو گئے۔ انہیں ایبٹ آباد کے پرفضا مقام پر سینی ٹوریم میں بھیج دیا گیا۔ وہاں
اُنہیں ایک تنور والی سے محبت ہو گئی۔ ظہور کسی طرح بھی اس قسم کی شادی پر رضامند
نہ ہو سکتے تھے اور کچھ ہی عرصے بعد نذیر نے صرف سترہ برس کی عمر میں ٹی بی کے مرض
سے فوت ہو گئے جسے شاید محبت میں ناکامی نے کچھ مزید بگاڑ دیا ہو۔ یہ حقیقی زندگی
میں کچھ ویسی درد بھری کہانی تھی جس قسم کی کہانیوں میں نذیر کے اُس بھتیجے نے
ہیرو کا کردار ادا کرنا تھا جس کی ابھی پیدایش نہیں ہوئی تھی۔
ظہور کی شخصیت کا صوفیانہ پہلو بیٹے کی تدفین کے موقع پر
سامنے آیا۔ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے بار بار خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ کسی نے
تعجب کا اظہار کیا تو ظہور نے کہا، "اگر خدا مجھ سے میرے بیٹے کو اُس کی
پیدایش کے سترہ منٹ بعد مجھ سے واپس لے لیتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ یا سترہ
مہینے بعد؟ میں خدا کا شکرگزار ہوں کہ اُس نے میرے بچے کو سترہ برس میرے پاس رہنے
دیا۔"
یہ ۱۹۳۰ء کی دہائی کے اواخر کی بات ہے۔ قریباً اُسی زمانے میں نذیر سے بڑے لڑکے، نثار، سیالکوٹ سے بمبئی چلے گئے۔ بظاہر وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ ظہور نے رفاہی کاموں میں وقت صرف کرنے کی وجہ سے بچوں کے لیے کوئی خاص اثاثہ جمع نہیں کیا تھا۔
نثار ۷ جون ۱۹۱۵ء کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ سنیما کا
عشق انہیں اگر بمبئی پہنچنے سے پہلے ہی نہیں ہو چکا تھا تو وہاں پہنچ کر ضرور ہو
گیا۔ برطانوی ہندوستان میں یہ فلم سازی کا سب سے بڑا مرکز تھا جس کے بعد کلکتہ اور
لاہور کا نمبر آتا تھا۔ بمبئی میں نثار نے فلموں کی تقسیم کاری کے ادارے انڈیا فلم
بروز میں ملازمت اختیار کر لی۔ جس طرح شیکسپئر کے زمانے کے انگلستان میں ڈرامے کو
معیوب سمجھتا جاتا تھا، اسی طرح برطانوی ہند میں مسلمانوں کے متوسط طبقے میں بھی
تھیٹر اور سنیما کو معیوب خیال کیا جاتا تھا اور ممکن ہے کہ نثار کے والد اُن کے
پیشے کے انتخاب پر خوش نہ ہوئے ہوں۔
بمبئی میں نثار کی ملاقات بیکانیر )راجستھان( کی ایک عیسائی خاتون سے ہوئی جو وہاں نرس کی خدمات
انجام دے رہی تھیں۔ خاتون نے اسلام قبول کر کے شیریں نام اختیار کیا اور نثار کے
ساتھ اُن کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد کسی وقت نثار کی پوسٹنگ کراچی ہو گئی اور وہ
بیگم کے ساتھ یہاں تشریف لے آئے۔
نثار اور شیریں کی واحد اولاد وحید مراد تھے جو ۲ اکتوبر
۱۹۳۸ء کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پیدایش کے وقت اُن کا نام
وحید احمد رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اُن کے دادا ظہور کا اپنے
بھائی ایف ڈی مراد سے کچھ اختلاف ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ظہور نے اپنی اولاد کے
ناموں میں لفظ "مراد" شامل کرنا ختم کر دیا تھا۔ اس لیے ان کے بڑے لڑکے
ظفر کے سوا باقی بچوں کے ناموں کے آخر میں پیدایش کے وقت مراد کی بجائے احمد کا
اضافہ کیا گیا۔ ظہور کی وفات کے بعد اُن کی اولاد نے ایف ڈی مراد کی اولاد کے ساتھ
تعلقات بحال کر لیے اور تب اپنے ناموں میں خاندانی لاحقہ "مراد" بحال
کیا۔ اس طرح نثار احمد بھی نثار مراد ہو گئے۔ اُن کے کمسن لڑکے کا نام بھی وحید
احمد سے وحید مراد ہو گیا۔
بہرحال اس سے پہلے ظہور الٰہی مراد فوت ہو چکے تھے۔ ان کا
انتقال سیالکوٹ میں ۱۰ نومبر ۱۹۳۸ء کو ہوا۔ ممکن ہے مقامی اخبارات میں یہ خبر شائع
ہوئی ہو لیکن اُنہی اخبارات میں ایک اور موت کی زیادہ بڑی سرخی بھی لگی ہو گی اور
وہ مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک کی تھی جنہوں نے ترکی میں اُسی دن وفات پائی تھی۔
بدھ، 18 نومبر، 2015
اشتیاق احمد، علامہ اقبال اور ہم سب
شائع کردہ بذریعہ
Khurram Ali Shafique
آج سے قریباً پینتیس برس پہلے کی بات ہے۔ ہر شخص سوگوار دکھائی دے رہا تھا۔ ابن صفی فوت ہو گئے تھے۔ میں ساتویں جماعت میں پڑھتا تھا اور مجھے مطالعے کا بہت شوق تھا۔ اس لیے جاننے والے مجھ سے بھی "تعزیت" کر رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں بھی ابن صفی کا مداح رہا ہوں گا کیونکہ مجھے مطالعے کا شوق تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں نے کبھی ابن صفی کو نہیں پڑھا تھا۔ دو تین دفعہ "عمران سیریز" کی شہرت سن کر محلے کی لائبریری سے سیریز کی کتاب حاصل کی لیکن معلوم نہیں تھا کہ ہر دفعہ ابن صفی کی بجائے کسی اور کی لکھی ہوئی کتاب میرے ہاتھ لگی ہے۔ ہر دفعہ وحشت ہوئی اور لاحول پڑھ کر کتاب واپس کر دی۔
میں اے حمید اور اشتیاق احمد کے ناول شوق سے پڑھتا تھا۔ ابن
صفی کی وفات کے بعد اشتیاق احمد کا پہلا ناول جو آیا وہ اگر میں بھول نہیں رہا تو
"تیسرا آدمی"تھا۔ اُس کی "دو باتیں" میں اشتیاق احمد نے بتایا
تھا کہ ابن صفی اُن کے روحانی اُستاد تھے۔ اب مجھے ایک دفعہ پھر کوشش کرنی پڑی اور
خوش قسمتی سے اس دفعہ ابن صفی کی اپنی تحریر ہاتھ لگی۔ "تلاشِ گمشدہ"،
جو ایک مسلسل کہانی کے بیچ کا ناول تھا اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ
کہانی سمجھ میں آتی۔ یہ ابن صفی کے قلم کی طاقت تھی کہ کوئی تشنگی محسوس نہیں
ہوئی۔ یوں ابن صفی سے میرا تعارف ہوا۔
اس کے بعد وہی ہوا جو میری جنریشن کے اکثر لوگوں کے ساتھ
ہوا۔ یعنی ابن صفی سے متعارف ہونے کے بعد ہم اشتیاق احمد سے وقتی طور پر دُور ہو
گئے۔ یہ اس لیے بھی تھا کہ اشتیاق احمد بچوں کے لیے لکھتے تھے۔ بچپن کی حدود سے
نکلتے ہی اُن کے ناولوں میں دلچسپی کچھ دیر کے لیے کم ہو جانا فطری بات تھی۔ ۱۹۸۱ء
میں آٹھویں جماعت کے زمانے میں میرے پاس اشتیاق احمد کی اُس زمانے تک شائع ہونے
والی تمام کتابوں کا مکمل ذخیرہ موجود تھا۔ یہاں تک کہ "ایک روپے والی"
مختصر کہانیاں بھی شامل تھیں۔ وہ سب میں نے نرسری مارکیٹ میں ہلال لائبریری کے عمر
بھائی کے ہاتھ معمولی داموں فروخت کر دیں۔ وہاں سے میرے ہی اسکول کے ایک لڑکے نے خریدیں جس سے اُس
وقت تک میرا تعارف نہیں ہوا تھا۔ بعد میں
مشترکہ دوستوں کے ذریعے متعارف ہوا۔ وہ میرے عزیز دوست اور نامور گلوکار فیصل لطیف
ہیں۔
چار پانچ برس بعد میں نے ناصرہ اسکول میں پڑھانا شروع کیا
تو وہاں کی لائبریری میں خاص طور پر اشتیاق احمد کے ناول رکھوائے اور بچوں میں
اشتیاق احمد کے ناولوں کی باقاعدہ تشہیر کی۔ البتہ یہ احتیاط کی کہ اُن کے وہ ناول
شامل نہ ہونے پائیں جن میں کسی گروہ کی دلآزاری کا کوئی پہلو موجود ہو۔ آسان ترکیب
یہ تھی کہ ۱۹۸۱ء سے پہلے کے ناول رکھے جائیں جن میں سے ایک ایک میرا پڑھا ہوا تھا۔
بالخصوص شیخ غلام علی اینڈ سنز سے اُن کے جو ناول شائع ہوئے تھے وہ نہ صرف بالکل
"مناسب" تھے بلکہ وہ میرے خیال میں دنیا بھر میں بچوں کے بہترین ادب کے
مقابلے میں رکھے جا سکتے تھے۔
میری اپنی طالب علمی کے زمانے میں اسکولوں کے اساتذہ اشتیاق
احمد کے ناولوں کی برائی کرتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اساتذہ کے ہاتھوں یہ
ناول پھٹتے ہوئے دیکھے تھے۔ اس لیے ۱۹۸۷ء میں جب میں نے ناصرہ اسکول میں بچوں کو
اشتیاق احمد کے ناول پڑھنے کی ترغیب دی تو بعض اساتذہ کو تعجب ہوا۔ خوش قسمتی سے اسکول کی انتظامیہ نے زبردست حمایت
کی جہاں محترمہ نصرت زبیری، محترمہ ناصرہ وزیر علی، محترمہ بلقیس صدیقی اور محترمہ
بیگم واجد علی جیسی روشن خیال ہستیاں جمع تھیں۔
پیش لفظ کا عنوان اشتیاق احمد کے ناولوں میں "دو
باتیں" اور ابن صفی کے ناولوں میں "پیشرس" ہوتا تھا۔ میں نے جب
اپنی کتابوں پر پیش لفظ لکھنے شروع کیے تو اِنہی دونوں کے امتزاج سے "پہلی
بات" کا عنوان ڈالا۔ لفظ "پہلی" ابن صفی کے "پیشرس" سے
ماخوذ ہے اور "بات" اشتیاق احمد کی "دو باتیں" سے درآمد کیا
گیا ہے۔میری کتابوں کے پیش لفظ کا عنوان عموماً یہی ہوتا ہے، "پہلی
بات۔"
بچپن میں اشتیاق احمد کے ساتھ میری خط کتابت رہی۔
اُن دنوں وہ خط کا جواب بڑی جلدی اور تفصیل سے دیتے تھے، نہایت باریک قلم سے بہت
ہی باریک لکھائی میں۔ پھر ناولوں میں بھی قارئین کے خطوط شائع ہونے لگے۔ میرے خطوط
بھی چند مرتبہ شائع ہوئے۔
جب پہلی دفعہ ایک کتاب کے پیچھے اشتیاق احمد کی تصویر چھپی تو
بعض پڑھنے والوں کو شدید دھچکا لگا۔ کچھ قارئین نے مشترکہ طور پر بہت ہی بدتمیز
قسم کا خط بھی لکھا جسے مصنف نے حسبِ معمول اگلے ماہ شائع کر دیا۔ اس پر دوسرے
قارئین نے خطوط لکھ کر اُن "بدتمیزوں" کی اچھی طرح خبر لی۔
انہی دنوں اشتیاق احمد ٹیلی وژن پروگرام "فروزاں"
میں بطور مہمان بلائے گئے۔ اس پروگرام میں قابل ذکر نوجوانوں کا تعارف کروایا جاتا
تھا۔ اشتیاق احمد سے پوچھا گیا کہ کیا کبھی کسی شخص کو دیکھ کر یوں لگا جیسے وہ اُن
کے ناول کا کوئی کردار ہے۔ اشتیاق احمد نے جواب دیا کہ ایک دفعہ اُنہیں بتایا گیا
کہ کراچی سے ایک نوعمر قاری اُن سے ملنے آیا ہے جس کا نام "فاروق احمد" ہے۔ اتفاق سے یہی نام اشتیاق احمد
کے ایک مرکزی کردار کا بھی تھا جس کی نمایندہ خصوصیت اُس کی حسِ مزاح تھی۔ اشتیاق
احمد نے کہا کہ جب وہ اس لڑکے سے ملے تو محسوس کیا جیسے وہ اپنے کردار فاروق سے مل
رہے ہوں۔
یہ انٹرویو دیکھ کر میں نے اشتیاق احمد کو خط لکھا اور
فاروق احمد کا پتہ مانگا۔ انہوں نے پتہ بھیج دیا اور یوں فاروق احمد سے میری قلمی
دوستی شروع ہوئی۔ ناظم آباد کی طرف کا پتہ
تھا اور میں پی ای سی ایچ میں رہتا تھا۔ ساتویں جماعت میں اکیلے اتنی دُور جانے کا
کوئی امکان نہیں تھا اس لیے ایک دو برس تک قلمی دوستی رہی۔ ملاقات کی نوبت نہیں
آئی۔
ایک مدت بعد یعنی چند برس پہلے کراچی کے کتاب میلے میں
"اٹلانٹس پبلی کیشنز" کے اسٹال پر معلوم ہوا کہ یہ ادارہ جو اَب اشتیاق
احمد کے ناول شائع کرتا ہے، اس کے کرتا دھرتا وہی فاروق احمد ہیں جن سے بچپن میں
میری قلمی دوستی رہ چکی ہے۔ ابن صفی کے فرزند ڈاکٹر احمد صفی اس موقع پر میرے ساتھ
موجود تھے۔ اُنہیں فاروق احمد سے متعارف کرواتے ہوئے میں اِس حسنِ اتفاق پر غور کر
رہا تھا کہ مجھے اشتیاق احمد نے ابن صفی سے متعارف کروایا اور پھر ابن صفی کے ورثا
کی اشتیاق احمد کے حلقے سے بالمشافہ ملاقات کروانے میں میرا حصہ ہو گیا۔
دو تین برس پہلےٹاپ لائن پبلشرز کے لیے درسی کتب کی سیریز "کتابِ
اُردو" مرتب کرتے ہوئے میں نے اشتیاق
احمد کی کہانی بھی شامل کی۔ فاروق احمد کے خصوصی تعاون کی بدولت یہ ممکن ہوا۔ یہ
کتابیں حال ہی میں شائع ہو گئی ہیں اور چند روز پہلے کراچی کے کتاب میلے میں ان کی
تقریبِ رونمائی ہوئی۔ ناشر حنین بن جبار نے مجھے بتایا ہے کہ میلے میں اُنہوں نے
اشتیاق احمد کی خدمت میں بھی یہ کتابیں پیش کیں۔ میں اِن دنوں ملک سے باہر ہوں مگر
حنین نے ان کتابوں پر نہ صرف اپنے لیے بلکہ میرے لیے بھی دستخط لیے۔ وہم و گمان
میں بھی نہ تھا کہ صرف دو روز بعد یہ ایک ایسی ہستی کے دستخط ہوں گے جو دنیا سے
رخصت ہو چکی ہے۔
مجھے اس بات سے کچھ تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے اشتیاق احمد کی
زندگی ہی میں یہ منظر اُن کے سامنے پیش کر دیا کہ اُن کی تحریر درسی کتابوں کا حصہ
بن رہی ہے۔ حنین کا کہنا ہے کہ وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔
اب صرف یہ خلش محسوس ہو رہی ہے کہ کاش مجھے اشتیاق احمد سے
یہ بھی کہنے کا موقع ملتا کہ اُن کی جاسوسی کہانی درسی کتاب میں اس لیے شامل کی جا رہی ہے کہ درسی کتابوں
کی یہ سیریز علامہ اقبال اور اُن کے شاگرد حکیم احمد شجاع کے
مرتب کردہ "اُردو کورس" کا ایک جدید رُوپ ہے۔ اصل سیریز ۱۹۲۴ء میں شائع
ہوئی تھی۔ اُس میں ایک جاسوسی ڈرامہ "ہوشیار سراغرساں" شامل کیا گیا
تھا۔ وہ حکیم احمد شجاع نے خود لکھا تھا۔ اسی لیے موجودہ سیریز میں چھٹی جماعت میں
اشتیاق احمد کی ایک کہانی، ساتویں جماعت میں ابن صفی کے ناول سے ایک اقتباس اور آٹھویں
جماعت میں شجاع کا ڈرامہ "ہوشیار سراغرساں" شامل کیے گئے ہیں۔
اِس طرح اُردو میں بچوں کا جاسوسی ادب متعارف کروانے کا
سہرا علامہ اقبال کے سر ہے۔ اس کی بنیاد رکھنے والے کا نام حکیم احمد شجاع قرار
پاتا ہے۔ اشتیاق احمد کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ اُنہوں نے بچوں کے ادب میں اُس صنف
کو دوبارہ زندہ کیا جسے علامہ اقبال نے متعارف کروایا تھا لیکن جسے بعد میں دانشوروں
نے بچوں کے ادب سے نکال دیا تھا۔
ہم نے اشتیاق احمد کو اِس کے صلے میں کیا دیا؟ اسکولوں میں
اُن کی کتابیں ممنوعہ قرار دی گئیں۔ اساتذہ نے اُنہیں پرزے پرزے کیا۔ کسی اکادمی،
کسی یونیورسٹی اور دانشوری کے کسی بٹیرخانے میں اُن کی پذیرائی نہیں ہوئی۔ اس کے
بعد اگر اشتیاق احمد اپنے ناولوں میں "انتہاپسندی" کی طرف راغب ہوئے تو
ہمیں تعجب کیوں ہے؟ تعجب تو ہمیں اس پر ہونا چاہئیے کہ انہوں نے اپنے پیٹ سے بم
باندھ کر خود ہی کو دھماکے سے کیوں نہیں اُڑا لیا۔
میں سمجھتا ہوں کہ ابن صفی نے کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے
زیادہ مفہوم ادا کرنے کی جو روایت قائم کی تھی، اُسے بھی اشتیاق احمد نے بچوں کے
ادب میں منتقل کیا۔ چونکہ بچوں کے ادب کے تقاضے نسبتاً محدود تھے اس لیے اشتیاق
احمد کے یہاں جزئیات نگاری مزید کم ہو گئی۔ یہ وہ اسلوب ہے جس سے اُس زمانے کی
انگریزی نثر بالکل محروم تھی۔ بڑوں اور بچوں دونوں کے ادب میں۔ میرے خیال میں انگریزی نے یہ اسلوب ڈَین براون
کے ساتھ متعارف ہوا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اُن کے پہلے تین ناول کوئی خاص توجہ
حاصل نہیں کر سکے کیونکہ وہ اُس جزئیات نگاری سے بالکل محروم تھے جو نقادوں کی
نگاہ میں کسی ناول کو ناول بناتی ہے۔ لیکن جب ڈَین براون نے "ڈا ونچی
کوڈ" میں عیسائیت کی دو ہزار سالہ تاریخ کا معمہ پیش کیا تو وہی جزئیات نگاری
سے محروم اسلوب اس معمے کو ہر طرح کے قارئین تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا۔
سچی بات یہ ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ "ڈا ونچی
کوڈ" پڑھا تو میرے دل میں اشتیاق احمد کی قدر بڑھ گئی۔ میں نے دوستوں سے کہا
کہ جس کارنامے پر دنیا عش عش کر رہی ہے یہ تو وہی اسلوب ہے جسے اشتیاق احمد ہمارے
بچپن کے زمانے سے استعمال کر کے اَدھ موا کر چکے ہیں، اس میں کون سی نئی بات ہے۔
بالکل اُسی طرح ڈَین براون کے کردار وں میں منہ سے بھی ایک ساتھ "اوہ"
نکلتا ہے اور وہ دفعتاً "اُچھل" پڑتے ہیں۔دروازے میں کوئی پراسرار شخص
کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے۔
اشتیاق احمد کے ناول ابن صفی کے ناولوں سے ایک اور طرح بھی
مختلف ہیں۔ ابن صفی نے اُس طرح کے ناول نہیں لکھے جیسے انگریزی میں لکھے جاتے ہیں
بلکہ ایک نئی صنف اختراع کی جس پر میں اپنی کتابوں "سائیکو مینشن" اور
"رانا پیلس" میں روشنی ڈال چکا ہوں۔ اس کے برعکس اشتیاق احمد کے ناولوں
میں سراغرسانی کا عنصر کچھ اُسی انداز میں پیش ہوتا ہے جیسا انگریزی کے جاسوسی
ناولوں کا انداز ہے۔ صرف اسلوب کا فرق ہے جو میں نے اوپر بیان کیا۔ یعنی وہ اسلوب
جو پہلے انگریزی میں موجود نہیں تھا اور پھر ڈَین براون کے ذریعے آیا۔ اس کے علاوہ مزاح اور اخلاقی پہلووں کا اضافہ ہے جو غالباً ابن
صفی کا اثر ہے۔
اس طرح اشتیاق احمد نے ابن صفی کی نقالی نہیں کی بلکہ ان سے
متاثر ہو کر اپنی الگ راہ نکالی۔ اسی لیے مجھے اُن کے آخری ناول "عمران کی
واپسی" کا اعلان سن کر زیادہ خوشی نہیں ہوئی البتہ اس بات کی خوشی ضرور تھی کہ
میرے پچپن کے قلمی دوست فاروق احمد، اشتیاق احمد کے ساتھ شریک مصنف بن گئے۔ میرے
خیال میں اشتیاق احمد کے بہت سے پرانے قارئین نے بھی یہی محسوس کیا ہو گا جیسے
فاروق ہم سب کی نمایندگی کر رہے ہیں اور ہم اشتیاق احمد کے ساتھ شریک ہو گئے
ہیں۔
اشتیاق احمد کے ناولوں کی تعداد آٹھ سو سے زیادہ ہے۔ کہتے
ہیں کہ یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ میرے خیال میں ناولوں کی تعداد سے قطعِ نظر بھی
اشتیاق احمد بہرحال ایک جینئیس تھے۔ صرف اُن ناولوں کی بات رہ جاتی ہے جن میں کچھ
ایسی باتیں ہیں جن سے بعض گروہوں کی دلآزاری ہوتی ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ
باتیں بچوں کے ناولوں میں نہ لکھی جاتیں تو بہتر تھا۔ لیکن یہ موضوع تفصیل طلب ہے۔
اس پر عاصم بخشی نے جو کچھ لکھا ہے اُسے حرفِ آخر بھی سمجھا جا سکتا ہے اور مزید
غور و فکر کے لیے نقطہء آغاز بھی۔ اُن کی یہ بات خاص طور پر قابلِ غور ہے کہ اُس
زمانے میں ہمارا بایاں بازو زیادہ لمبا ہو گیا تھا۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اشتیاق
احمد دائیں بازو کو بھی اُتنا ہی لمبا کر کے تناسب بحال کر سکے یا نہیں۔ لیکن اب
جبکہ اُن کی کتابوں کی اشاعت فاروق احمد کے سپرد ہے، ہم توقع کر سکتے ہیں کہ دونوں
بازو برابر ہو کر حدِ اعتدال میں واپس آ جائیں گے۔
میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اشتیاق احمد کی کتابیں سینسر کر کے
شائع کی جائیں۔ مطلب یہ ہے آٹھ سو ناولوں میں ہر طرح کے ناول موجود ہیں۔ انتخاب
کیا جا سکتا ہے۔
پیر، 9 نومبر، 2015
کیا علامہ اقبال کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا گیا؟
شائع کردہ بذریعہ
Khurram Ali Shafique
بچپن میں اکثر سنا تھا کہ علامہ اقبال نے نظم "شکوہ" لکھی تو
مولویوں نے اُن پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ تحقیق کرنے پر کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے۔ اس کے برعکس "شکوہ" کے صرف ایک برس
بعد ۱۹۱۲ء میں "شمع اور شاعر" سنانے سے پہلے علامہ نے جو تمہیدی کلمات
کہے اُن سے کسی حد تک اس بات کی تردید ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا:
"جو نظم پچھلے سال لکھی تھی وہ شکوہ تھا اور اُس میں خدا سے شکایت تھی اور بعض لوگوں نے اُسے برا خیال کیا اور یہ سمجھا کہ یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ میں نے بھی یہی خیال کیا لیکن تو بھی وہ اِس قدر مقبول ہوئی کہ آج تک کئی ہزار خطوط اس کی تعریف کے میرے پاس آچکے ہیں۔ اِس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہی بات جو کہ لوگوں کے دلوں میں تھی وہ ظاہر کر دی گئی لیکن میں خیال کرتا ہوں کہ میرا شکوہ خدا کو بھی پسند آیا۔"
اِنہی الفاظ سے یہ مشہور بات بھی غلط ثابت ہوتی ہے کہ نظم "جوابِ
شکوہ" علامہ کو صرف اِس لیے لکھنی پڑی کہ "شکوہ" پر بڑے اعتراض
ہوئے تھے۔ اول تو "شکوہ" اتنی پسند کی گئی تھی کہ "جواب"
لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہے "شکوہ" کا جواب
علامہ نے "شمع اور شاعر" کو قرار دیا تھا جو "شکوہ" کے ایک برس
بعد پیش کی گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ "جوابِ شکوہ" نظم "شکوہ"
کے قریباً پونے دو برس بعد لکھی گئی۔ شانِ نزول یہ تھی کہ جنگِ بلقان کے لیے چندہ
اکٹھا کرنا تھا اور "شکوہ" کی مقبولیت کے پیشِ نظر توقع تھی کہ اُس کے
"حصہ دوم" سے اس نیک کام میں بڑی مدد ملے گی۔ چنانچہ مشہور روایت کے
برعکس "شکوہ" کی مقبولیت "جوابِ شکوہ" کی وجہ معلوم ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ "جوابِ شکوہ" میں علامہ نے جو کچھ کہا ہے وہی سب کچھ وہ
پچھلے چار پانچ برسوں میں نظم و نثر میں کہتے آ رہے تھے۔
ان تمام حالات کی مستند تفصیلات آپ میری کتاب "اقبال: تشکیلی دور"
میں ملاحظہ کیجیے جسے انٹرنیٹ سے مفت ڈاون لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ علامہ کی
زندگی کے ایک خاص زمانے یعنی ۱۹۰۵ء سے ۱۹۱۳ء کی مکمل ترین سوانح ہے لیکن اپنی جگہ
ایک مکمل کتاب بھی ہے۔
اب آئیے کفر کے فتوے کی طرف۔ علامہ کے خلاف کفر کا صرف ایک فتویٰ موجود ہے جو
روزنامہ زمیندار میں ۱۹۲۵ء میں شائع ہوا۔ وہاں سے اسے عبدالمجید سالک نے علامہ کی
سوانح "ذکرِ اقبال" میں شامل کیا۔ وہاں سے دوسری تصانیف میں منتقل ہوا
جن میں ڈاکٹر جاوید اقبال کی "زندہ رُود" بھی شامل ہے۔ اتفاق سے حال ہی
میں "اقبال: دورِ عروج" مکمل کرتے ہوئے مجھے اپنے محترم دوست امجد سلیم
علوی کی مہربانی سے زمیندار کے متعلقہ صفحات کا عکس ملا تو کچھ نئی چیزیں سامنے
آئیں جنہیں "ذکرِ اقبال" میں بھی نہیں بتایا گیا اور وہ دوسری کتابوں
میں بھی نظرانداز ہو گئی ہیں۔
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فتویٰ مسجد وزیر خاں کے خطیب مولوی دیدار علی سے
لیا گیا مگر مولوی صاحب نے اسے مشتہر نہیں کیا تھا۔ ایک شخص نے انہیں خط میں لکھا
کہ اگر کوئی شخص ایسے ایسے اشعار کہے تو کیا وہ کافر ہے؟ ساتھ ہی علامہ کے بعض
اشعار لکھ دئیے [ان میں "شکوہ" کا کوئی شعر شامل نہیں تھا]۔ جواب میں
مولوی صاحب نے لکھا کہ جی ہاں، ایسے اشعار کہنے والا کافر ہے۔ یہ فتویٰ روزنامہ زمیندار نے ایک تعارفی نوٹ کے ساتھ یہ
کہہ کر شائع کیا کہ اس کی اصل اخبار کے دفتر میں محفوظ ہے۔
اب دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ "استفتا" یعنی فتویٰ لینے والے کے
تفصیلی سوال میں کہیں علامہ کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ اس لیے یہی معلوم ہوتا ہے کہ
فتویٰ دیتے ہوئے مولوی صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ اشعار کس کے ہیں۔ غالباً انجانے
میں انہوں نے فتویٰ دیا اور نہیں جانتے تھے کہ کس کے خلاف فتویٰ دے بیٹھے ہیں۔
تیسری بات یہ ہے کہ اُن دنوں زمیندار کے مالک و مدیر مولانا ظفر علی خاں اپنے
نائب غلام رسول مہر کے ساتھ ملک سے باہر تھے۔ اخبار کا کام نوجوان ادارت کا تمام کام عبدالمجید سالک نے
سنبھال رکھا تھا جن کی زندہ دلی مشہور تھی۔ وہ اور زمیندار کا
ادارہ ان دنوں سلطان ابن سعود کی حمایت کر رہے تھے جبکہ مولوی دیدار علی سمیت
بریلوی صاحبان اکثر سعودیوں کے مخالف تھے۔ مولوی صاحب ویسے بھی کفر کے فتوے دینے
میں مشہور تھے۔ یوں لگتا ہے کہ زمیندار کے ادارے نے مولوی صاحب کو شرمندہ کرنے کے
لیے اس طرح اُن سے فتویٰ لیا کہ ایک فرضی نام سے سوال بھجوایا گیا۔ سوال میں علامہ
کا نام نہیں لیا گیا۔ علامہ کے مشہور ترین اشعار کی بجائے بعض ایسے اشعار لکھے گئے
جو صرف کتابوں اور رسالوں میں شائع ہوئے تھے، جلسوں میں نہیں پڑھے گئے تھے۔ فتویٰ
حاصل کر کے اس لیے شائع کیا گیا کہ علامہ اقبال اُس وقت ہندوستان کے اُن چند
مسلمانوں میں سے تھے جن کے خلاف کفر کے فتوے کا تصوّر ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔
اس طرح فتویٰ لے کر دراصل مولوی صاحب کے ساتھ ایک طرح کا مذاق کیا گیا کہ یہ
تو علامہ اقبال کو بھی کافر کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کے باقی فتوے بھی غلط ہوں گے۔ اس
کے بعد زمیندار میں ایک طویل مضمون مولوی صاحب کے فتوے کے خلاف شائع ہوا جس میں
علامہ کے اشعار کی تشریح کر کے ان کا دفاع کیا گیا تھا۔ یہ مضمون اگرچہ مصنف کے
نام کے بغیر شائع کیا گیا مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ علامہ کے خاص الخاص شاگرد
چودھری محمد حسین سے لکھوایا گیا تھا۔
بظاہر یہ اس فتوے کا اصل پس منظر معلوم ہوتا ہے اگرچہ اس پر مزید تحقیق کی
ضرورت ہے کہ فتویٰ شائع ہونے کے بعد مولوی دیدار علی صاحب نے بھی کوئی بیان دیا۔
ویسے یہ معلوم ہے کہ چار برس بعد غازی علم الدین کی نمازِ جنازہ کے موقعے پر علامہ
نے نمازِ جنازہ پڑھانے کے لیے انہی کا نام تجویز کیا تھا۔ میرا اپنا خیال یہی ہے
کہ اگر مولوی صاحب کو معلوم ہوتا کہ اُن سے جن اشعار پر رائے لی جا رہی ہے وہ
علامہ اقبال کے ہیں تو شائد وہ کفر کا فتویٰ نہ دیتے۔
اِس قصے کی باقی تفصیل میری آیندہ کتاب "اقبال: دورِ عروج" میں پڑھی
جا سکتی ہے، جسے میں آج کل مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انشاء اللہ جلد ہی
دستیاب ہو گی۔
اضافہ: "اقبال: دورِ عروج" مکمل ہو چکی ہے اور ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔
اضافہ: "اقبال: دورِ عروج" مکمل ہو چکی ہے اور ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔